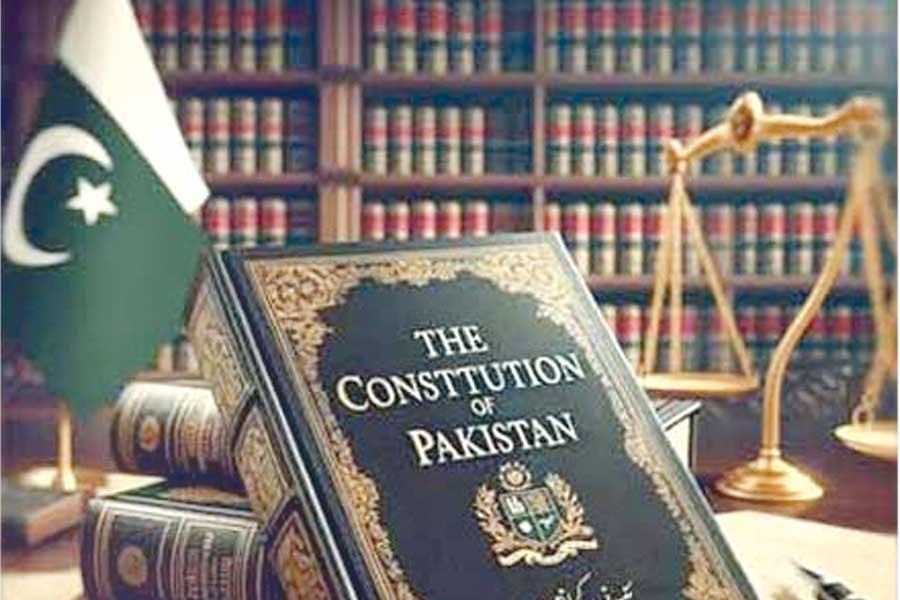دنیا الٹ گئی تھی، شمالی پاکستان میں قیامت برپا تھی۔ میں جنوبی بندرگاہی شہر کراچی میں تھا جب وہ غیر متوقع فون آیا۔
“کیا آپ اسلام آباد آئیں گے؟ زلزلے کی کوریج کے لیے آپ کو تعینات کیا جا رہا ہے،” میرے ایڈیٹر نے پوچھا۔
میرے پاس انکار کی گنجائش نہیں تھی۔ میں نے ہامی بھر لی۔ بے خبر کہ میں پاکستان کی جدید تاریخ کے سب سے ہولناک المیے کا گواہ بننے جا رہا ہوں۔
8 اکتوبر 2005 کا زلزلہ، جس نے لمحوں میں شمالی پاکستان کو ملبے کا ڈھیر بنا دیا۔ تقریباً ایک لاکھ افراد ہلاک ہوئے، ہزاروں کے اعضا کاٹنے پڑے، اور لاکھوں بے گھر ہو گئے جن کے گھر زمین بوس ہو گئے۔ میں فوری طور پر اسلام آباد کی پہلی فلائٹ پر سوار ہوا۔
بیورو ایک شور میں ڈوبا ہوا تھا، رپورٹرز، فوٹوگرافرز، ٹیکنیشن، سب تباہ شدہ علاقوں میں روانگی کی تیاریوں میں لگے تھے۔ مجھے باغ بھیجا گیا، ایک سرحدی قصبہ جس کا نام بھی میں نے اس دن پہلی بار سنا تھا۔ ہماری گاڑی میں بسکٹ، جوس، پانی، چپس اور سلیپنگ بیگز رکھ دیے گئے۔ ایک نامعلوم سفر کے لیے۔
راستے پہاڑی تھے، بل کھاتے، اور معلوم نہیں کہاں ٹوٹے ہوئے۔ جب ہم جہلم دریا پر تان ڈھلکوٹ پل سے گزر کر کشمیر میں داخل ہوئے تو تباہی کی اصل تصویر سامنے آئی۔پہاڑیوں کے دونوں اطراف گاؤں ملبے میں بدل چکے تھے۔سڑک کنارے کھڑے لوگ مدد کے منتظر تھے۔ ہم رکے تو انہوں نے سمجھا شاید ہم ریسکیو ٹیم ہیں۔
میں نے بچوں میں بسکٹ اور چپس بانٹے، ایک معمولی سا مگر بے بس عمل جو پورے دن دہراتا رہا، یہاں تک کہ سارا سامان ختم ہو گیا۔
جب ہم باغ پہنچے تو شہر مٹی کے ڈھیر میں تبدیل ہو چکا تھا۔گھر، اسکول، اسپتال، سرکاری دفاتر، حتیٰ کہ فوجی چھاؤنی تک، سب تباہ۔ ایک گورنمنٹ اسکول کے ملبے پر مائیں بیٹھ کر رو رہی تھیں۔تین دن گزر چکے تھے، کوئی امداد نہیں پہنچی تھی۔وہ روتیں، خاموش ہوتیں، پھر دوبارہ روتیں۔
کسی نے بتایا کہ کل تک ملبے کے نیچے سے بچوں کی آوازیں آ رہی تھیں، مگر اب وہ بھی خاموش ہو چکی تھیں۔پھر بھی ماؤں کی امید زندہ تھی، ٹوٹی ہوئی مگر سانس لیتی ہوئی۔
ڈچ ریسکیو ٹیم اپنی نارنجی وردیوں میں پہنچی تھی، ان کے چھوٹے ڈرل مشینیں موٹے کنکریٹ کے سامنے بے بس تھیں۔
ہم شہر کے کنارے ایک پٹرول پمپ پر پہنچے، تباہ شدہ شہر کی واحد زندہ نشانی۔ وہیں سے میں نے اسٹوری فائل کرنا شروع کی، اور فوٹوگرافر نے اپنی تصویریں۔ اتنے میں میری نظر پڑی، میرے سیٹلائٹ فون کے ساتھ ایک اور فون چارجر سے لگا ہوا تھا۔2005 میں عام آدمی کے لیے ایسا فون نایاب تھا۔
میں نے دیکھا، تھوڑی ہی دیر بعد ایک نوجوان قریب آیا، لمبی ڈاڑھی، ٹخنوں سے اونچی شلوار، ہاتھ میں تسبیح۔اس نے بتایا کہ اس کا نام حمزہ ہے، جماعت الدعوۃ سے تعلق رکھتا ہے، جو کشمیر میں سرگرم سمجھی جاتی تھی۔حمزہ بے تکلف تھا۔ اس نے بتایا کہ زلزلہ آنے کے چند گھنٹے بعد وہ اور اس کے ساتھی سب سے پہلے متاثرہ علاقوں میں پہنچے اور امداد شروع کی۔ہماری بات چیت میں اس نے مجھے جہاد میں شامل ہونے کی دعوت دی۔ میں نے کہا،جو کام میں کر رہا ہوں، وہ بھی جہاد سے کم نہیں۔ میں دنیا کو بتا رہا ہوں کہ یہاں کیا قیامت گزری ہے۔وہ مسکرایا، جیسے کچھ سمجھ گیا ہو۔
شام ڈھل رہی تھی۔اس نے ہمیں رات گزارنے کے لیے مسجد کا مشورہ دیا۔مسجد کا ہال نرم قالینوں سے بھرا تھا، مگر آدھا گنبد گر چکا تھا، اور کسی بھی وقت باقی حصہ بھی زمین بوس ہو سکتا تھا۔ہم نے شکریہ ادا کیا اور رخصت ہوئے۔جاتے جاتے اس نے ایک چھوٹا سا لائٹر دیا، جس میں ایک باریک سی روشنی تھی”اندھیرے میں کام آئے گا”، اس نے کہا۔
رات سڑک کے کنارے SUV میں گزری۔باہر شدید سردی، اندر دم گھٹتا تھا۔جب شیشے بند کرتے تو ہوا رک جاتی، کھولتے تو ٹھنڈ جسم میں اترتی۔آخرکار ہم پیدل چلنے لگے، اندھیرے میں، محض پہاڑوں کے سائے اور سڑتی لاشوں کی بو کے سہارے راستے کا اندازہ لگاتے ہوئے۔
حمزہ کے دیے ہوئے لائٹر کی روشنی ہماری رہنمائی کر رہی تھی۔بالآخر ہمیں سڑک کے کنارے ایک کنکریٹ کا تختہ ملا، چھت نہیں تھی مگر محفوظ لگا۔ہم نے وہاں سلیپنگ بیگ بچھا دیے۔آسمان صاف تھا، ستاروں سے بھرا ہوا۔ میں نے بیگ کا زپ سر تک کھینچ لیا، سردی سے بچنے کے لیے۔پھر گھٹن نے مجبور کیا کہ سر باہر نکالوں، یوں پوری رات سردی اور دم گھٹنے کے بیچ گزری۔ کبھی کبھی آنکھ لگ جاتی تھی۔
صبح ہوئی تو وادی سبز تھی، مگر فضا سوگوار۔ہم دوبارہ اسکول پہنچے،اب کچھ ریسکیو ٹیمیں کام شروع کر چکی تھیں۔ کچھ رضاکار چائے لے آئے، شاید کہیں سے۔
وہی مائیں اب بھی وہاں تھیں، مگر ان کی چیخوں میں اب خوف نہیں، تسلیم کی ٹھنڈی راکھ تھی ۔ اپنے بچوں کے انجام کو قبول کرتی، مگر پھر بھی ملبے کے پاس بیٹھی رہتی تھیں، جیسے ابھی بھی کوئی معجزہ ہو جائے۔
زلزلے کے ملبے تلے
انسانیت کا امتحان
اذیت ناک مناظر ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے، مگر کام جاری رکھنا ضروری تھا۔ ہم تباہ حال قصبے کا چکر لگانے نکلے۔ سڑکیں بند تھیں اور گاڑیاں چلنے کے قابل نہیں تھیں، اس لیے ہم نے پہاڑی راستوں پر پیدل چلنے کا فیصلہ کیا۔ تیز دھوپ کے نیچے لوگ اپنے زخمی عزیزوں کو چارپائیوں پر کندھوں پر اٹھائے جا رہے تھے۔ فضا میں خاموشی اور مایوسی چھائی ہوئی تھی۔
اب جب میں یہ سب لکھ رہا ہوں تو احساس ہوتا ہے کہ پہاڑی علاقوں میں سورج کی شعاعیں میدانی علاقوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ تیز ہوتی ہیں، اسی لیے دھوپ اتنی بے رحمانہ محسوس ہو رہی تھی۔ اسی کھلی دھوپ کے نیچے زخمی لوگ بے یار و مددگار پڑے تھے۔ چوتھے دن تک کئی افراد کے ہاتھ، پاؤں ٹوٹے ہوئے تھے، زخم سڑنے لگے تھے اور ایسا لگتا تھا جیسے جلد ہی یہ زخم ایک وبا کی شکل اختیار کر لیں گے۔
ایک نوجوان سفید کوٹ پہنے میری طرف دوڑتا ہوا آیا۔ پہلی نظر میں میں نے سمجھا کہ وہ ڈاکٹر ہے۔ اس نے پوچھا، “ہم اپنا میڈیکل کیمپ کہاں لگائیں؟” اُس نے بتایا کہ وہ کراچی سے اپنی ایک رضاکار ٹیم کے ساتھ آیا ہے، اپنے ساتھ درد کم کرنے والی دوائیں اور زخموں کے لیے طاقتور جراثیم کش دوا پوویڈون لایا ہے۔ چونکہ وہاں کوئی سرکاری امدادی عملہ موجود نہیں تھا، وہ سمجھتا تھا کہ ہم بہتر جانتے ہوں گے کہاں ضرورت زیادہ ہے۔ میں نے اسے مرکزی سڑک کے قریب ایک جگہ تجویز کی جہاں لوگ جمع تھے، اور پھر آگے بڑھ گیا۔
کچھ دور ایک شخص تنہا سڑک کنارے چل رہا تھا۔ ہم نے ایک دوسرے کو سلام کیا۔ جب اُسے معلوم ہوا کہ ہم میڈیا سے ہیں تو اُس نے پہاڑیوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، “اُدھر ایک گاؤں تھا، جو اب نہیں رہا۔ زیادہ تر لوگ مر گئے۔” اُس کی اردو نہایت شستہ تھی، لہجہ پرسکون ،حد سے زیادہ پرسکون۔ میں نے اُس سے اُس کے خاندان کے بارے میں پوچھا۔ اُس کا چہرہ یک دم بدل گیا، آنکھوں میں آنسو اُمڈ آئے۔ اُس نے آہستگی سے کہا، “وہ سب جا چکے ہیں۔”
اُس لمحے ضبط اور غم کے درمیان فاصلہ مٹ گیا۔ ہمارے گرد زندگی اور موت ایک ساتھ سانس لے رہے تھے۔ جو بچ گئے تھے، اُنہیں اپنے مرنے والوں کا سوگ منانے کی مہلت نہیں ملی تھی۔ اب اُنہیں اپنی زندگی بچانے کی فکر تھی۔
ہم آگے بڑھے تو ایک ٹرک آیا جس میں امدادی سامان لدا ہوا تھا۔ لوگ بھاگ کر اُس کے گرد جمع ہو گئے، ہر کوئی کچھ حاصل کرنے کی کوشش میں تھا۔ یہ امداد ایک غیر سرکاری تنظیم نے بھیجی تھی، مگر تقسیم شروع ہونے سے پہلے ہی ایک مقامی سیاستدان اپنے ساتھیوں سمیت وہاں پہنچ گیا۔ امدادی عمل روک دیا گیا۔ ایک سرکاری اہلکار نے اُسے آہستہ سے مشورہ دیا کہ راولاکوٹ سے ایک بینر آ رہا ہے جس پر اُس سیاستدان کا نام اور عہدہ درج ہے، جب تک وہ بینر ٹرک پر نہیں لٹکایا جاتا، سامان تقسیم نہ کیا جائے۔
میں یہ سب دیکھتا رہا، بھوکے، تھکے اور ٹوٹے ہوئے لوگ سیاست کی رسومات پوری ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ ایک ہی دن میں میں نے انسانی کمزوری، خودغرضی اور برداشت کے اتنے سبق سیکھے جتنے شاید پوری زندگی میں نہ سیکھ پاتا۔ المیہ بہت بڑا تھا، مگر چھوٹی چھوٹی سفاکیاں ،انا، بے حسی، اور طاقت کا تکبر ،کہیں زیادہ گہری چوٹ مار رہی تھیں۔
مسکراہٹ کی اوٹ
صبر اور عزم کا دکھ
چند دن گزر چکے تھے کہ ہم مظفرآباد میں کسی حد تک سنبھل گئے تھے۔ ریلیف ٹیمیں آ چکی تھیں، اور ہمیں بھی چھوٹے چھوٹے پیراشوٹ ٹینٹ مل گئے تھے، جن میں بمشکل ایک شخص سما سکتا تھا۔ میں نے اپنا ٹینٹ لگانے سے پہلے اردگرد کا جائزہ لیا۔ زلزلے کے جھٹکے اب بھی آ رہے تھے، اس لیے ضروری تھا کہ کسی ایسی پکی عمارت سے دور جگہ چنی جائے جو کسی وقت گر سکتی تھی۔
رات کو بارش شروع ہوئی ،ایک مسلسل، بےرحم بارش۔ اس کے قطروں کی ٹپ ٹپ ٹینٹ کے کپڑے پر ایسے بج رہی تھی جیسے کوئی دھات پر انگلیاں بجا رہا ہو۔ میں سلیپنگ بیگ میں لیٹا ہوا اس آواز کو برداشت کرتا رہا۔ لیکن جلد ہی ایک ٹھنڈک سی پاؤں کے قریب محسوس ہوئی۔ بارش کا پانی اندر رِسنے لگا تھا۔ پہلے پاؤں، پھر کمر، پھر کندھے تک سب بھیگ گیا۔ مجبوراً میں رات کے پچھلے پہر ٹینٹ سے باہر نکل آیا۔
بارش تیز تھی، جیسے آسمان برسنے کے لیے بیتاب ہو۔ میں گاڑی میں جا بیٹھا، مگر بارش کی بوندیں اس کی چھت پر ایسے گر رہی تھیں جیسے گولیوں کی بوچھاڑ ہو۔ قریب ہی ایک درخت تھا ،زیادہ گھنا تو نہیں، مگر اتنا ضرور کہ سیدھی بارش سے بچا سکے۔ میں بار بار گاڑی اور درخت کے درمیان آتا جاتا رہا، بھیگتا، کانپتا، اور طلوعِ سحر کا انتظار کرتا رہا۔
آخر جب روشنی پھیلی تو بارش بھی تھم گئی۔ میں نے اپنا بھیگا ہوا ٹینٹ اور سلیپنگ بیگ سکھانے کے لیے پھیلایا۔ اسی دوران میری نظر تین چار بچوں پر پڑی جو ایک ڈھلوان پر کھیل رہے تھے۔ ان کی معصوم ہنسی عجب سکون دیتی تھی، مگر اردگرد کوئی بڑا دکھائی نہ دیا۔ یہ بات مجھے چونکا گئی۔ ان دنوں خبریں گردش کر رہی تھیں کہ کئی یتیم بچے اسمگلروں کے ہاتھوں اغوا کیے جا رہے ہیں۔ میں احتیاطاً ان کے قریب گیا اور پوچھا کہ ان کے والدین کہاں ہیں۔
تھوڑی ہی دیر میں ایک عورت کہیں سے نمودار ہوئی۔ اس نے بتایا کہ بچے اس کے ہیں۔ میں نے دریافت کیا کہ وہ لوگ ابھی تک یہاں کیوں ہیں جب کہ زیادہ تر خاندان راولپنڈی یا کسی محفوظ مقام کی طرف جا چکے تھے۔ اس نے کہا کہ اس کا شوہر کرایے کے پیسے جمع کر رہا ہے۔ ٹرانسپورٹرز موقع سے فائدہ اٹھا رہے تھے اور مسافروں سے کئی گنا زیادہ کرائے وصول کر رہے تھے۔
میرے پاس کچھ رقم تھی۔ میں سوچنے لگا کہ کتنی مدد کر سکتا ہوں۔ شاید میری ہچکچاہٹ چہرے پر عیاں تھی۔ عورت میری طرف دیکھتی رہی ،جیسے وہ میرے ارادے کو تول رہی ہو۔ پھر اچانک وہ مسکرائی۔
اور اُس لمحے میں اندر سے بُری طرح ہل گیا۔ وہ مسکراہٹ، جس میں التجا اور شکست دونوں چھپی تھیں، میرے دل پر نقش ہو گئی۔ میں نے محسوس کیا کہ اپنے بچوں کی بقا کے لیے وہ عورت خود کو بیچ دینے پر آمادہ تھی۔ انسان کی بےبسی کا یہ لمحہ میرے اندر کہیں گہرائی تک اُتر گیا ، ایک ایسا منظر جسے کوئی کیمرہ قید نہیں کر سکتا۔
میں نے جلدی سے جیب سے کچھ روپے نکالے اور اس کے حوالے کر دیے۔ کچھ دیر بعد اس کا شوہر بھی آ گیا۔ وہ بتانے لگا کہ زلزلے کے بعد کس طرح وہ اپنے گاؤں سے پیدل چل کر یہاں پہنچے۔ میں سنتا رہا، خاموشی سے۔ ناشتے کے بعد میں اور میرا فوٹوگرافر شہر کے ٹوٹے ہوئے حصوں میں کہانیاں تلاش کرنے نکل گئے۔ شام کے قریب واپس آئے تو دیکھا وہی خاندان اپنا سامان سمیٹ رہا ہے۔
سورج ڈھلنے کو تھا جب میں نے انہیں جاتے دیکھا ،مرد اور عورت سر پر گٹھڑیاں اٹھائے، پیچھے بچے قدم ملا کر چلتے ہوئے۔ ان کے چہروں پر تھکن تھی، مگر ایک عزم بھی۔ میں ان کو دیکھتا رہا، خاموشی سے۔ اچانک اس عورت کی نگاہ مجھ سے ملی۔ وہ پھر مسکرائی۔
لیکن اس بار وہ مسکراہٹ مختلف تھی۔ اس میں شکرگزاری تھی، اطمینان تھا۔ صبح کی وہ مجبوری اس کے چہرے سے مٹ چکی تھی۔ شاید میرے دیے گئے چند روپوں کی وجہ سے نہیں، بلکہ اسے اپنا وقار بحال رکھنے کی آسودگی تھی۔
میں دیر تک انہیں جاتا دیکھتا رہا۔ سورج پہاڑوں کے پیچھے اتر چکا تھا، اور افق پر سرخی پھیل گئی تھی ،ایک ایسی روشنی جو جانے والے دن کی تھکن میں بھی کل کے اُجالے کی اُمید جگا رہی تھی۔
جب پہاڑ لرز اٹھے: 2005 کے زلزلے کی چشم دید داستان